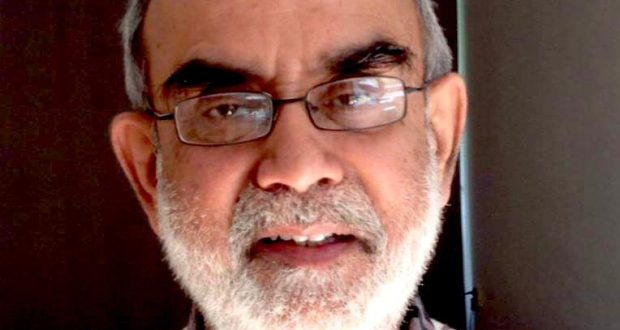بیسویں صدی کی عالمی سیاست بنیادی طور پر یورپی نو آبادکاروں کے خلاف قومی مزاحمتوں کی سیاست تھی۔ جب آپ قومی آزادی کی ان جنگوں کا منظر دیکھتے ہیں تو در اصل دو نہیں تین مناظر دیکھنے کو آتے ہیں۔ مسلح طاقت سے سیاسی تبدیلی لانا۔ عوامی طاقت کے پر امن اظہار سے بیرونی تسلط کے خلاف لڑنا ،اور علم کی طاقت سے آزادی کا راستہ تلاش کرنا- ان تین طرح کے مناظر کو سمجھنے کے لئے سیاست، جنگ اور علم کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے۔
سیاست، جنگ اور علم تینوں دنیا کو بدلنے کے مختلف طریقے ہیں۔ علم کا کام فرق کرنا سکھانا ہے۔اور فرق کرنا سکھا کے لوگوں کے دلوں میں زندگی کو بدلنے کی لو لگانا ہے۔ علم کا راستہ اس امید پر چلتا ہے کہ محکوم اور حاکم دونوں کو اپنے خوف سے آزادی کی ضرورت ہے۔ اور یہ آزادی کوئی ایک فریق تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ آزادی ایک مشترک آدرش ہے اور یہ بیک وقت وو نوں متحارب فریقوں کو مل سکتی ہے یا کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس طرح سے تبدیلی کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔
علم جنگ کے نقطہ نظر سے بھی ایک دلچسپ امکان پیش کرتا ہے۔ بقول چینی مرد دانا سن ز±و کے اگر آپ کو اچھی طرح اپنی طاقت کا علم ہو اور اپنے دشمن کی طاقت کا بھی علم ہو تو آپ بغیر جنگ کیے اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں- تشدد لازم±ی نہیں ہوتا۔
سیاست اور جنگ کے راستے میں تشدد کو مرکزی اہمیت حاصل رہتی ہے۔ اقتدار یا آزادی حاصل کرنے کا مقصد بھی تشدد کے ہتھیاروں کے استعمال کا اخلاقی اور قانونی حق حاصل کرنا ہوتا ہے۔اس نظریے کے مطابق تشدد کی طاقت سماجی اونچ نیچ کے فرق کو بڑھانے یا مٹانے کا کام کرتی ہے-یہ طاقت ریاست کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔سیاست ریاستی قوت پرقبضہ کرنے کا حق لینے کی لڑائی ہے۔ گاندھی کے خیال میں ریاستی قوت حاصل کرنے کی لڑائی میں عدم تشدد کے ہتھیار سے ریاستی تشدد کو مات کیا جا سکتا ہے۔اور ماوزے تنگ کے خیال میں جنگ سیاست کی انتہائی طاقتور شکل ہے۔ ان دونوں نظریوں کی بنیاد اور ان کے طریقہ کار چند دلچسپ نفسیاتی اور سیاسی مفروضوں پر قائم ہیں۔
جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ریاستی قوت صرف جنگ کے ذریعے سے ہی حاصل نہیں ہو سکتی۔انسانوں اور انسانی گروہوں کے درمیان فرق خوف کا ذ ریعہ بھی بن سکتا ہے اور امید کا بھی۔خوف جنگ کی طرف لے جائے گا۔ اور امید امن کی طرف۔ خوف اور امید کا انسان کے اپنے اور دوسروں کے بارے میں علم سے تعلق ہے۔انسان کو اپنے ادھورے ہونے کا احساس ہو تو دوسرے اس کے لئے پورے ہونے کی امید لے کے آتے ہیں۔ اور انسانی تعلق کی بنیاد امن اور تعاون بن جاتا ہے۔ اگر دوسروں سے خوف ہو کہ وہ ہماری خوشحالی اور خوشی کے حصے دار بن کر ہماری مسرتوں میں کمی نہ کر دیں تو تعلق تشدد اور جنگ میں بدل جاتا ہے۔
بیسویں صدی کی سیاسی اور سماجی لڑائیاں انسانوں کے درمیان خوف کا اظہار تھیں۔ ایک طرف یورپ کی فاتح اقوام تھیں جنہوں نے دوسرے دیسوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کو غلام بنا لیا۔دوسری طرف ان مفتوح دیسوں کے باغی عوام تھے۔ سوال یہ تھا کہ یورپی قوموں کا یہ ظالمانہ قبضہ کیسے ختم کیا جائے؟ گاندھی کا نظریہ تھا کہ ہتھیار رکھنے والی ریاستی طاقت کا بغیر ہتھیار کے مقابلہ کیا جائے۔تو ریاست کو تشدد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔اور تشدد کے استعمال کو نیچے لا کے محکوم اور حاکم اعتماد اور برابری کی بنیاد پر بات کر سکیں گے۔ اور ان کے ٹکراوکا فیصلہ ان کی نفسیاتی قوت اور نفسیاتی ہتھیاروں کے ذریعے ہو گا۔ اس سٹریٹجی سے گاندھی نے انگریزوں کو اپنے منتخب کردہ میدان میں لڑنے پر راضی کر لیا۔ اور نفسیاتی اور اخلاقی طور پر ان کو کمزور پوزیشن میں ڈال دیا۔ اور اپنی مہارت سے انہیں مغلوب کر لیا۔ لیکن یہ عدم تشدد صرف ایک سیاسی معرکہ میں انہیں قبول تھا۔جسے اُس نے ایک سیاسی سٹریٹجی اور نفسیاتی ہتھیار کے طور پر تو قبول کیا لیکن ایک عمو می اخلاقی اصول کے طور پر اختیار نہیں کیا۔اس نے ایک “ہندستانی” قوم کے لئے عدم تشدد کا علم بلند کیا۔ لیکن جب اچھوتوں نے جدا گانہ انتخاب کا حق مانگا۔تو اس نے مرن بھرت کی دھمکی دے کر ان کے لئے گلیوں بازاروں میں خون خرابے کا خطرہ پیدا کردیا۔ اچھوتوں کے رہنما ڈاکٹر امبیدکر مرتے دم تک اس تلخ حقیقت پر دکھی رہا اور بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس نے گاندھی پر منافق ہونے کا الزام لگایا۔ گاندھی نے انگریز سے تو عدم تشدد کی بات کی لیکن پانچ ہزار سال سے موجود تشدد پر مبنی ذات پات کے نظام سے چھٹکارے کو دھرم پر حملہ قرار دیتا رہا۔ امبیدکر کے بقول وہ دوغلا تھا۔ گجراتی میں ذات پات کے حق میں لکھتا تھا اور انگریزی میں اس سے الٹ بات کرتا تھا۔ وہ اس دو رنگ سیاست سے اس قدر مایوس ہو گیا کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس نے اپنے دس لاکھ پیروکاروں سمیت بدھ مذہب اختیار کر لی۔
قومی آزادی کے دوسرے رہنماوں یعنی کمیونسٹوں انقلابیوں میں بھی تشدد اور عدم تشدد کی سیاست کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔انڈونیشیا اور چلی کی کمیونسٹ پارٹیوں نے عدم تشدد کی سیاست میں مقبولیت حاصل کی اور لاکھوں کارکنوں کی زندگیوں کی قربانی دے کر روپوشی اور جلا وطنی اختیار کی۔ ہندستان میں کمیونسٹوں نے پرامن طریقے سے کیرالہ اور بنگال میں حکومتیں بنائیں لیکن ان کی مسلح لڑائی کی سیاست کامیاب نہیں ہوسکی۔ملایا کے کمیونسٹ 1930 کی دہائی میں ہی انگریزوں کے خلاف ایک شاندار گوریلا جنگ ہار گئے۔ فلسطین، کشمیر اور خالصتان کی مسلح تحریکیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ آئر لینڈ اور جنوبی افریقہ کے جنگجو پرامن طریقے سے سیاسی نظام میں داخل ہو گئے۔ اور افغانستان کے پہاڑوں میں نیم مسلح جنگجو بیس سال تک 43 ملکوں کی فوجوں سے لڑنے کے بعد بغیر کسی مزاحمت کے کابل پر قابض ہو گئے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسا عنصر یہ طے کرتا ہے کہ تشدد کی سیاست کامیاب ہو گی یا عدم تشدد کی۔ بیسویں صدی میں تو ایک اہم پہلو ہے جس نے طے کیا ہے کہ مزاحمت کامیاب ہو گی یا نہیں چاہے مزاحمت مسلح ہو یا غیر مسلح۔ نوآبادیاتی اور سرمایہ داری نظام میں جب ریاستی طاقت پر قبضہ قائم رکھنا غیر منافع بخش ہو جائے تو قبضہ ختم ہو جاتا ہے۔
اب آئیے پاکستان کے ماو سوچ رکھنے والوں کی طرف۔ماوسٹ ایک خونی انقلاب میں یقین رکھتے تھے۔ اس میں وہ ناکام کیوں ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سب ناتجربہ کار تھے۔ ان کی سیاسی سوجھ ب±وجھ کمزور تھی۔ وہ پاکستانی ریاست کی قوت ، معاشرے میں موجود طبقاتی طاقت کی شکلوں اور اپنی محدود صلاحیتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔یہ کمزوریاں اب بھی موجود ہیں۔ لیکن سب سے نمایاں کمزوری فکری قیادت کی کمزوری ہے۔پاکستان کے خونی انقلاب کے پیروکاروں کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ ایک وسیع البنیاد قومی سطح کی جنگجو جماعت نہیں بنا سکے۔ جیسے کہ ماوزے تنگ نے کہا تھا اگر عوام کی پارٹی نہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ان میں قیادت کی صلاحیت نہیں ہے۔
اِن انقلابیوں کو دانشوروں، ٹریڈ یونین محاذ ، عوامی ایجی ٹیشن ، طالب علم سیاست، وکیلوں اور شہروں کے لوگوں میں پذیرائی رہی ہے۔ وہ نظام کے لئے درد سر تو بن گئے اسے گرانے کی ان میں صلاحیت پیدا نہیں ہو سکی۔نہ ہی وہ اپنی کوئی عوامی پارٹی بنا سکے۔ مزدور کسان پارٹی نے بھی مسلح لڑائی کی سیاست کی اور ان کے دعوے کے مطابق ان کے دو سو کارکنوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دی۔ لیکن وہ پاکستانی ریاست اور طبقاتی نظام کے لئے کوئی چیلنج نہیں بن سکی۔
پاکستان میں مغربی نیشن سٹیٹ کی طرح ریاست کی تشدد پر اجارہ داری نہیں ہے۔اور ریاست نے تشدد کے نظام پر اجارہ داری قائم بھی نہیں کی۔ بلکہ یہاں تشدد کا غیر ریاستی اداروں کے ذریعے سے منظم طور پر استعمال ریاستی پالیسی کا حصہ رہا ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے قبائلی اسلحہ بردار، جاگیر داروں کی نجی بندوقیں، دہشت گرد تنظیمیں، اور دہشت گرد سیاسی گروہوں کو استعمال کیا، تشکیل دیا اور ا±ن کی سرپرستی کی۔ البدر اور الشمس، ایم کیو ایم اور مسلح مذ ہبی گروہوں کا قیام اسی فکر کا تسلسل رہے ہیں۔ اس تشدد کے جواز کے لئے مذہب کا کارڈ بھی استعمال کیا گیا، دستور توڑنے کا اور حب الوطنی اور کرپشن کے نام پر اس جھوٹ کی پردہ پوشی کرنے کا، اور دستور میں ترمیم کرنے کا بھی۔ ریاست نے مسلح کسان قوت کا ماوسٹ نظریہ ہتھیا کر مجاہدین اور طالبان کی قوت قائم کردی اور اربن گوریلا وار فئیر کا نظریہ چوری کر کے ایم کیوایم بنا دی۔ ترقی پسند دانشور دائیں بازو کے ریاستی اور غیر ریاستی تشدد کے اداروں کے گٹھ جوڑ کا سیاسی جواب نہیں ڈھونڈ سکتے-
پاکستانی معاشرے کو تشدد کی سیاست کے بغیر بھی بدلا جا سکتا ہے۔لوگوں کی حاکمیت قائم کی جا سکتی ہے۔ ہتھیاروں اور ووٹوں کی سیاست جو تبدیلی نہیں لا سکی وہ علم، شراکت اور انکساری کی اخلاقیات کے ذریعے ممکن ہے۔
 Sangat Sangat is a popular opinion, columns and blogs website.
Sangat Sangat is a popular opinion, columns and blogs website.